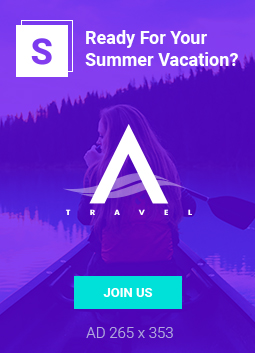گیارہ جون بروز بدھ(2013ء)
میں شدیدذلت کے احساس سے دو چار تھا۔ زندگی میں پہلی بار یوں کسی نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور مجھے گالی دی تھی۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے اور میں بے آواز روئے جا رہا تھا۔ مرتضیٰ مجھے کالر سے پکڑ کر اس کار والے سے معافی مانگنے کا کہہ رہا تھااور میرے اندر اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ سر اٹھا کر کسی کی آنکھوں میں دیکھ سکوں ۔ ہوٹل پر چائے پینے والوں کے ساتھ ساتھ سڑک پر پیدل چلنے والوں نے بھی یہ منظر دیکھا تھا۔ میری ٹانگوں سے چپکے ہوئے چھوٹوکو میں نے بار بار اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا۔ ایک وہی تھا جو اس وقت میری آنکھوں میں دیکھ سکتا تھا۔
کار والا مجھے تھپڑ مارنے کے بعد گالیاں بکتے ہوئے چلا گیا تھا ۔
میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اس شہر میں میرا پہلا دن اتنا بد ترین ہو گا۔ مجھے رہ رہ کر اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی۔ میں چاہتا تھا اُڑ کر اس کے پاس پہنچ جاؤں اور اسے بتاؤں کہ مجھ پر کیا بیتی ہے‘ مگر یہ صرف میری خواہش تھی۔حقیقت یہ تھی کہ میری جیب میں واپسی کا کرایہ تک نہیں تھا۔
اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک مرتضیٰ مجھے سناتا رہا ۔ چھوٹو بار بار میرے پاس آ جاتا اور کسی نہ کسی بہانے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا‘ مگر میں اس سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ غریبی جس پر مسلط ہوتی ہے‘ سب سے پہلے اس کی عزت نفس کواپنا شکار بناتی ہے اور اکثر و بیشتر یہ کامیاب ہو جاتی ہے ۔لوگ جب ایک بار اپنی عزت نفس مار لیتے ہیں۔ ان کے لیے جینا آسان ہو جاتا ہے‘ مگر جو لوگ غربت کا شکار ہو کر بھی عزت نفس کو نہیں مرنے دیتے اُن کی زندگی کا ہر آنے والالمحہ پہلے سے زیادہ کڑا اور صبر آزما بن جاتا ہے۔ یہ عزت نفس کو بچاتے ہیں تو دنیا انہیں جینے نہیں دیتی اور مار دیتے ہیں تو خود جی نہیں پاتے ۔
عزت نفس کا تقاضا تھا کہ مجھے ابھی مرتضیٰ کے منہ پر تھوک کر واپس گھر چلے جانا چاہیے یا کہیں اور جا کے رہنا چاہیے۔۔
مگر میری غریبی مجھ سے کچھ اور ہی کہتی تھی۔ اس دن مجھے اپنی غربت سے سخت نفرت ہو گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں کبھی اپنی قسمت سے جھگڑتا، تو کبھی اپنے مرے ہوئے باپ کو کوسنے لگتا جس نے مجھے پیدا کر کے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ کبھی میں اللہ سے شکوہ کناں ہو جاتا‘ تو کبھی دنیاسے … بے بس انسان صرف خود سے لڑ سکتا ہے ،میں بھی خود سے لڑ رہا تھا۔
اپنی کم مائیگی کا ،اپنی بے وقعتی کا احساس مجھے کھائے جا رہا تھا۔ میں نے کئی بار دل میں تہیہ کیا… میں ابھی جا کر اس مرتضیٰ نامی آدمی سے کہوں گا ’’تم ہوتے کون ہو مجھ سے معافی منگوانے والے؟ تم کیا اندھے تھے ؟ دیکھ نہیں رہے تھے پانی انڈیلتے وقت میں سڑک پر نہیں دیکھ رہا تھا؟ اور مجھے سڑک پر پانی پھینکنے کا کس نے کہا؟ تم نے کہا… اور اس کار والے کے سامنے بھیگی بلی بن کر الٹا مجھے ہی کوسنے لگے تھے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر اور تمہارے اس گھٹیا ہوٹل پر جسے دیکھ کر لوگ تھوکنا بھی پسند نہیں کرتے۔‘‘
میں نے یہ بھی سوچا کہ میں ابھی اس کار والے کی محل نما کوٹھی پر پہنچ جاوؑں اور اس کے گھر میں گھس کر اسے چار پانچ تھپڑ مار کر اپنا بدلہ اتار لوں‘ مگر میں صرف سوچ سکتا تھا۔ سچ یہ تھا کہ میں تھپڑ اور گالیاں کھانے کے بعد اب چائے کی گندی پیالیاں دھو رہا تھااور بار بار اُمڈ آنے والے آنسوؤں کو بے دردی سے پونچھ رہا تھا۔
رات کے دس بج چکے تھے ۔ ہوٹل کے آس پاس چہل پہل کم ہو گئی تھی‘ مگر مہران اسٹریٹ پر ٹریفک اب بھی پوری رفتار سے چل رہا تھا۔ مرتضیٰ نے مجھے اور چھوٹو کو لوہے کے بنچ ،کرسیاں اور ٹیبل اکٹھے کر کے اندر رکھنے کو کہا اور خود پھٹے پر پاؤں پسار کر لیٹ گیا۔ میں نے چھوٹو کے ساتھ مل کر ہوٹل کے تمام پھیلاوے کو سمیٹنے کے بعد چھوٹو کو لیٹ جانے کو کہا۔
’’آپ بھی سو جاؤ بھا جی… دن میں بھی ٹھیک سے آرام نہیں کیا۔‘‘
چھوٹو نے میری آنکھوں کی سوجن سے نظریں چرا کر کہا تھا۔
’’نہیں یا ر… مجھے ابھی نیند نہیں آئے گی تو سو جا۔‘‘
میں نے حتی الامکان کوشش کی تھی کہ میری آواز نہ بھیگے مگر میرا لہجہ خود بخود ہی گلوگیر ہو گیا۔
’’بھا جی اس کار والے کو آپ کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ آپ کی غلطی نہیں تھی ۔‘‘
میں نے چھوٹو کی بات سنی‘ مگر کچھ کہنے سے گریز کیا۔
’’پر آپ چنتا نئیں کرو بھا جی… وہ روز رات کو دیر سے گزرتا ہے یہاں سے جس دن مجھے موقع مل گیا‘ ایک شیشہ بھی ثابت نہیں رہنے دوں گا اس کی گاڑی کا۔ ڈھونڈتا پھرے گا اندھیرے میں پھر کہاں سے پتھر آیا اور کس نے مارا؟‘‘
چھوٹو غضبناک ہو رہا تھا۔میں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔
’’نہیں چھوٹو … پھر اس میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟‘‘
چھوٹو نے حیران ہو کر مجھے دیکھا۔
’’تو بھا جی یہی تو میں چاہتا ہوں کہ فرق نہ رہے اس میں اور ہم میں۔ اس نے آپ کو تھپڑ مارا‘ آپ اور میں مل کر اس کی گاڑی کے شیشے توڑ دیں گے۔ تب آپ کو رونا نہیں آئے گا جیسے اب آ رہا ہے ۔‘‘
چھوٹو نے اپنے تئیں بہت سمجھداری کی بات کی تھی اور اب مجھے داد طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔
’’نہیں چھوٹو ! ہم ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے جس سے مرتضیٰ چاچا کے لیے کوئی مصیبت کھڑی ہو ۔‘‘
میں نے چھوٹو کو اس کے ارادوں سے باز رہنے کے لیے کہا۔ اس نے جو کہا تھا وہ کر سکتا تھا‘مگر میں جانتا تھا کہ اس طرح مرتضیٰ کا یہ چھپر ہوٹل بند ہو جائے گا اورایسا میں نہیں چاہتا تھا۔
’’استاد تو خود مصیبت ہے بھا جی… مجھے کئی بار بلا وجہ پیٹ چکا ہے۔ ایک دو بار تو گاہکوں سے بھی پٹوا چکا ہے اور ایک بار مجھ سے راستے میں دودھ گر گیا‘ تو پورے ایک گھنٹے تک یہاں سڑک پر مرغا بنائے رکھا اور مہینے کے بعد تنخواہ میں سے پیسے بھی کاٹ لیے۔ بھا جی یہ رشتے میں میرا دور کا ماموں لگتا ہے۔ میرے اماں ابا کے مرنے کے بعد اس نے برادری میں سب کے سامنے میرا ذمہ اُٹھایا تھا۔ تب میں سمجھا تھا کہ یہ مجھے میرے ماں باپ کی طرح رکھے گا ،مگر دو مہینے بعد یہ مجھے یہاں لے آیا۔‘‘
چھوٹو کے انکشافات دل دہلا دینے والے تھے ۔ وہ یتیم اور بے آسرا بچہ مرتضیٰ جیسے گھٹیا آدمی کے رحم و کرم پر تھا۔ میں نے اس کے گال تھپتھپا کر اسے سونے کے لیے کہا اور خود ہولے ہولے کچے پکے رستے پر چلنے لگا۔ تھکاوٹ کے باوجود نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، مجھے رہ رہ کر وہ منظر یاد آرہا تھا جب کار والے نے مجھے تھپڑ مارا۔ مجھے اس کی گالیاں بھی یاد آ رہی تھیں ۔ خود کو اکیلا پاتے ہی میں نے اونچی آواز کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ میری ہچکی بندھنے لگی اور میں مسلسل رو رہا تھا۔ کبھی کبھی سامنے سے کوئی گاڑی آتی تو دو سیکنڈ کے لیے میرا متورم چہرہ روشن ہو جاتا‘ مگر مجھے اب پروا نہیں تھی۔ میں ایک ہی بار کھل کر رو لینا چاہتا تھا تا کہ آنے والے دنوں کی کٹھنائیاں آسانی سے برداشت کر سکوں۔ شاید اس طرح میرے دل کا بوجھ کچھ کم ہو جاتا۔ چلتے چلتے میں کافی دور آ چکا تھا۔ میرے بائیں طرف لوہے کی تار سے بنی ہوئی باڑھ شروع ہو گئی۔ یہ اس ایریا میں بنے ہوئے پارک کی حد بندی کے لیے لگائی گئی تھی۔ باڑھ کے ساتھ ہی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر سیمنٹ کے بنے ہوئے بنچ تھے جہاں شام کے وقت لوگ بیٹھ کر گپیں ہانکتے تھے۔ میں سڑک کے بیچوں بیچ چلتے ہوئے اب باڑھ کراس کر کے بنچ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ جب سامنے سے آنے والی گاڑی نے مجھے سڑک کی دوسری طرف جانے پر مجبور کر دیا۔ میں نے ہیڈ لائٹس کی روشنی سے بچنے کے لیے سڑک کی دائیں طرف دیکھا جہاں وقفے وقفے سے کوٹھیاں بنی ہوئی نظر رہی تھیں۔ میری نظریں تھوڑی دیر کے لیے اس محل کے مین گیٹ پر آویزاں روشن بورڈ پر ٹک گئیں جس پر جلی حروف میں ’’کریم پیلس‘‘ لکھا ہوا تھا۔
گاڑی گزر چکی تھی۔ میں نے سڑک کی بائیں طرف جا کر باڑھ پھلانگی اور بنچ پر جا کے بیٹھ گیا۔
میرے آنسو تھم چکے تھے۔
میں اس وقت بالکل خالی الذہنی کی کیفیت میں مبتلا تھا۔
’’ماں آج اکیلی سو رہی ہو گی۔‘‘
تھوڑی دیر بنچ میں بیٹھنے کے بعد میں نے یاسیت سے سوچا۔
’’کتنی اداس ہو گی میرے بغیر ‘ سو کہاں رہی ہو گی۔ کروٹیں بدل رہی ہو گی وہ بھی اور سوچ رہی ہو گی کہ اس نے مجھے شہر بھیج کر ٹھیک کیا یا غلط؟‘‘
میں نے تصور میں ماں کا چہرہ لا کر اسے دیکھنے کی کوشش کی‘ مگر سارے منظر دھندلا سے گئے ،سب کچھ مکس ہو گیا۔
’’یہ رات کیسے کٹے گی؟‘‘
میں نے بوجھل دل سے سوچا تھا۔
کبھی کبھی وقت رک جاتا ہے۔ ہماری شدید خواہش کے باوجود ٹلنے کا نام نہیں لیتا ۔ ہم طرح طرح کے جتن کر کے اسے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں‘ مگر یہ ہم پر مسلط ہو جاتا ہے۔ یہ رات بھی مسلط ہو چکی تھی۔ ٹلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مجھے یہاں بیٹھے دو گھنٹے سے زیادہ ہو گئے تھے ۔ آج کی تاریخ کل میں بدل چکی تھی ۔
’’ایک سیاہ دن کا اختتام۔‘‘
میں نے نفرت سے زمین پر تھوکا۔
جیسے وہ دن تھوک بن کر میرے حلق میں اٹک گیا ہو۔
چھوٹے سے پارک کے پیچھے مہران اسٹریٹ پر اب گاڑیوں کا ہجوم کم ہو چکا تھا اور میرے سامنے والا رستہ جو مرتضیٰ کے چھپر ہوٹل پر ختم ہوتا تھا بالکل سنسان اور تاریک ہو گیا تھا۔
’’میری زندگی بھی اس رستے کی طرح سنسان ہے ۔۔‘‘
اک اور مایوس سوچ۔۔۔۔۔۔ سوچیں جب مایوس ہونے لگیں ۔ یہ آپ کو زنگ آلود کر دیتی ہیں اور صلاحیتیں سلب کر لیتی ہیں۔
میں نوجوان تھا ،تندرست بھی تھا ‘مگر ایک آزمایش بھرے دن نے میری سوچ میں مایوسی بھر دی تھی ۔
میں نے آنکھیں بند کر لیں ۔
آنکھیں بند کرلینے سے ہم تھوڑی دیر کے لیے اندھیرے میں چلے جاتے ہیں ،ہر طرف اندھیرا اور رات کے بارہ بجے یہ اندھیرا اور بھی گہرا لگتا ہے ۔
میں نے سانس لے کر سوچ کے نقطے کو زیرو پر لانے کی کوشش کی۔ میں گزرے ہوئے کل کو بھول کر ایک نیا دن شروع کرنا چاہتا تھا۔ جب میرے آس پاس گھاس پر بکھرے خشک پتے چرچرا ئے… میں نے چونک کر آنکھیں کھول دیں ۔
مہران اسٹریٹ پر پارک کی پچھلی باڑھ کے ساتھ چند ساعتوں کے لیے ایک موٹر سائیکل رکا۔ دو کھلنڈرے لڑکوں نے ٹارچ کی روشنی مجھ پر ڈالی اور زور سے سیٹی بجاتے ہوئے آگے بڑھ گئے ۔
میں نے اُن کے غائب ہونے تک موٹر سائیکل کا نظری تعاقب کیا اور ایک گہری سانس لی۔
جب ایک مدھم‘ مگر پتھریلی آواز میرے بہت پاس سے سنائی دی۔
’’آئی ایم سوری۔‘‘
میں نے چونک کر سامنے دیکھا۔ اندھیرے میں اک ہیولا سا کھڑا تھا۔ جیسے کوئی انسان ہو۔ اس کی آواز بھی انسانوں جیسی تھی۔
ہاں یقینا!
لڑکیوں جیسی آواز تھی‘ مگر اس آواز میں انسان سے زیادہ کسی روبوٹ کا …
کسی کمپیوٹرائزڈ ریکارڈڈ آواز کا گمان ہوتا تھا۔
میں بے اختیار اُچھل کے کھڑا ہو گیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس انجان جگہ پر ایک سنسان پارک میں رات کے بارہ بجے میرے علاوہ اور کون قسمت کا مارا ہو سکتا تھا؟
کوئی پاگل؟ یا پھر مافوق الفطرت وجود…
مجھے بچپن میں ماں کے سنائے ہوئے تمام بھوت پریت کے قصے اور کہانیاں یاد آنے لگیں ۔
’’کون ؟‘‘
میں بوکھلاہٹ میں صرف اتنا ہی کہ پایا۔
وہ ہیولا خاموش کھڑا تھا۔ نہیں … کھڑی تھی۔ اس کے بال اور دوپٹا بتاتے تھے کہ وہ کوئی لڑکی ہو سکتی تھی۔ یا کوئی پچھل پیری…
میں نے گھبرا کر اس کے پیروں کی طرف دیکھا اور سکھ کا سانس لیا۔ وہ پچھل پیری نہیں تھی ۔
پر وہ جو بھی تھی اس نے چند لمحوں کے لیے مجھے گزرے ہوئے تاریک دن سے باہر نکال لیا تھا ۔
اور یہی تو میں چاہتا تھا۔
٭…٭…٭
گیارہ جون بروز بدھ (2013ء)
تکیہ پوری طرح بھیگ چکا تھا۔ مگر اس کی تسلی اب بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔
حساس لوگوں کی سب سے بڑی مشکل یہی ہے۔ یہ ہمیشہ ان باتوں پر اٹک جاتے ہیں جو دنیا کے لیے ’’اک ذرا سی بات‘‘ ہوتی ہیں۔
بات اک ذرا سی تھی۔ اس کے باپ نے چھپر ہوٹل کے فقیر جیسے حلیے والے لڑکے کو تھپڑ مار دیا تھا اور اب سکون سے ٹی وی دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ ’’اک ذرا سی بات‘‘ تھی۔
مگر تکیہ اچھی طرح بھگو کر بھی لڑکے کا خوفزدہ چہرہ نہیں بھول پا رہی تھی وہ حساس لڑکی۔ جو دکھنے میں دنیا سے بے نیاز تھی۔
اس نے کھڑے ہو کر دوپٹا اوڑھا اور دروازہ کھول کر تھرڈ فلور سے ہوتے ہوئے چھت پر اپنی مخصوص جگہ پہنچ گئی ۔
کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔
وہی ٹریفک۔۔۔۔ وہی چلتے پھرتے لوگ۔۔۔۔ وہی سیٹیاں بجاتے موٹر سائیکل سوار۔۔۔۔ وہی نکڑ پر استادہ پیپل کا درخت۔۔۔۔ اور اس کے نیچے بنا ہوا چھپر ہوٹل ۔۔۔۔۔
اس نے اندھیرے میں غور سے ہوٹل کو دیکھنے کی کوشش کی‘ مگر کچھ نظر نہیں آیا۔
اس سے پہلے کبھی یہ پیپل کا درخت اور یہ فقیروں کی جھگی جیسا دکھنے کا والا ہوٹل اس کی نظروں کا محور نہیں بنا تھا۔
وہ خاموشی سے کھڑی ہو کر ٹریفک کو تکے جایا کرتی تھی۔ مگر آج وہ اس ہوٹل کو بار بار دیکھ رہی تھی جس کے اندروہ چہرہ موجود تھا۔ بچوں کی طرح سہما ہوا بے قصور اور معصوم چہرہ اور پھر اک زوردار تھپڑ اس کے کانوں میں گونجا۔
اس نے پلکوں کی جھالر سے ایک بارپھر امڈ آنے والے ڈھیر سارے آنسوؤں کو روکنا چاہا۔ مگر آنسو اس کے اختیار میں صرف دنیا کے سامنے ہوتے تھے۔
تنہائی پاتے ہی بے لگام ہو جاتے تھے ۔
ایک اجنبی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ ’’آج ہی گاؤں سے آیا ہے صاب ۔‘‘
’’کیا کیا خواب سجا کے آیا ہو گا گاؤں سے ؟ پڑھنے کی عمر میں نوکری کرنے کے لیے آ گیا۔ گھر والوں نے بھیجا ہو گا۔ گھر والے؟۔۔۔۔۔ماں باپ…
یہی تو ہوتے ہیں گھر والے۔ اور کون ہو سکتا ہے ؟
میں اس کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہی ہوں ؟ اور سب بھی تو تھے وہاں جب اسے تھپڑ پڑا تھا۔ سب کے سب میری طرح رو رو کر ہلکان تو نہیں ہو رہے ہوں گے ؟اتنا تو وہ خود بھی نہیں رو یا ہو گا۔‘‘ ذہنی رو اسے بہائے لے جا رہی تھی۔
اس بہاؤ میں تب رکاوٹ پڑی جب اسے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں گھر کے باہر والی سڑک پر دور سے روتا ہوا ایک چہرہ نظر آیا۔
اسے لگا یہ وہی ہے ۔
گاڑی گزر چکی تھی ،سڑک پر پھر سے اندھیرا چھا گیا،مگر وہ سست قدموں سے چلتا ہوا اس کے گھر کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔
رانی کی نظریں اندھیرے میں چلتے ہوئے ہیولے پرجم چکی تھیں اور پھر وہ عین اس کے گھر کے سامنے پہنچا جب ایک اور گاڑی گزری ،ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اس نے اسے گھر کے گیٹ کی طرف ہوتے دیکھا۔ وہ پہچان چکی تھی کہ یہ وہی لڑکا تھا۔ لمبا تڑنگا‘سانولے رنگ والاجس نے قمیص کے دونوں بازو تب بھی فولڈ کیے ہوئے تھے اور اب بھی۔ گاڑی گزر جانے کے بعد وہ کریم پیلس کی مخالف سمت چلا گیا اور باڑھ پھلانگ کر پارک کے بنچ پر بیٹھ گیا۔ ’’وہ رو رہا تھا؟‘‘ اس نے حیرت سے سوچااور پھر سے نظریں اس پر جما لیں۔
وہ اب دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ ’’کیا اسے پتا ہو گا‘یہ اس شخص کے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھا ہے جس نے آج اسے ذلیل کیا تھا؟‘‘
’’مجھے اس کے بارے میں اتنا نہیں سوچنا چاہیے ۔‘‘
اس نے سر جھٹک کر اس کا خیال دل سے نکالنے کی کوشش کی اور رفتہ رفتہ کم ہوتے ٹریفک کو دیکھنے لگی ‘مگر وہ خود بھی انجان تھی کہ وہ بار با ر اسی بنچ کو دیکھ رہی ہے ۔
’’مجھے کیا کرنا ہے ابھی ؟‘‘ اس نے تنگ آ کر سوچا۔
’’جیسے پہلے کرتی تھیں ۔‘‘
کوئی اس کے اندر سے بولا۔
’’نہیں…‘‘ اس نے اپنی ہی بات کو جھٹلاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔
’’گھر میں رہنے والوں کی بات اور ہے ۔ فاطمہ آنٹی ،ان کا بیٹا اکبر ۔۔۔۔۔کمال چاچا ۔۔۔۔۔شکور ۔۔۔۔۔ان سب سے اور بات ہے ۔ ان کے ہاتھوں میں پلی بڑھی ہوں میں‘ مگر ایک انجان لڑکے سے پاپا کی غلطی کی معافی ؟نہیں یہ ٹھیک نہیں ہو گا۔‘‘
وہ خود کو باور کرا رہی تھی ۔
’’تو پھر ایسے ہی بے حس بن کر کھڑی رہو ۔جھوٹے ٹسوے مت بہاؤ۔‘‘ اس کے اندر کی حد درجہ ضدی لڑکی نے بے رحمی سے مشورہ دیا تھا اسے۔
’’میں جھوٹے آنسو نہیں بہا رہی ۔مجھے سچ مچ دکھ ہے اس بے قصور لڑکے کی بے عزتی کا ۔‘‘
اس نے جھٹ سے اپنی سچائی بتائی تھی۔ ’’تو پھر ثابت کرو کے تمہیں دکھ ہے۔جاؤ مانگ لو معافی ۔ تمہارا باپ تو کبھی نہ مانگے گا اس سے ،اُلٹا اسے یہاں بیٹھا دیکھ کر اور بھی ذلیل کر دے گا۔ موقع اچھا ہے۔چپ چاپ جاؤ اور معافی مانگ کے واپس آ جاؤ ۔پہلے کی طرح بہتر ہو جاؤ گی ۔‘‘
وہ چپ ہو گئی۔
اب اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ اپنی عدالت میں ایک بار پھر خود سے ہار گئی تھی۔
یہ بہت مشکل ہے۔ اپنی عدالت میں پیش ہونا۔
اپنے بے قصور ہونے کے لیے چیخنا چلانا اور پھر سچ کوتسلیم کر کے سر خم کر لینا۔
اپنی ہی عدالت میں اپنے ہاتھوں اپنی شکست لکھنے والی وہ لڑکی دنیا کی نظر میں مغرور اور اپنوں کی نظر میں ذہنی معذور تھی اور یہی اس کا سچ تھا۔ کڑوا سچ۔۔۔۔۔
اس نے دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترنا شروع کر دیں تھیں۔
اس کے باپ کے کمرے کی لائٹ بجھ چکی تھی ۔ گھر کے مین گیٹ پر پہنچی‘ تو ایک سائیڈ پر رکھی کرسی پر اونگھتا ہوا کمال چاچا ہڑبڑا کر اُٹھ کھڑا ہوا۔
’’کیا ہوا چھوٹی مالکن ؟‘‘ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ اس نے کمال چاچا کو دیکھا۔
کمال چاچا نے اک بار گیٹ کھولنے میں ایک منٹ کی دیر کر دی تھی ۔
اور اسی رات اپنے باپ کے کمرے کی لائٹ بجھنے کے بعد وہ اس کے پاس آئی تھی‘معافی مانگنے۔
’’مجھے باہر جانا ہے ۔‘‘
اس کے دو ٹوک انداز سے کمال چاچا اچھی طرح واقف تھا۔
’’پر چھوٹی مالکن… اس وقت تو بہت دیر ہو گئی ہے۔ باہر سے کچھ لانا ہے تو مجھے بتا دیں؟ اس نے ہچکچا کر کہا تھا۔
’’ میں باہر پارک تک جا رہی ہوں۔پانچ منٹ میں واپس آ جاؤں گی ۔‘‘
اس نے کمال چاچا کی حیرانگی کو نظر انداز کر کے کہا۔ کمال چاچا پریشان ہو گیا تھا۔
’’چلیں میں آپ کے ساتھ ہی چلتا ہوں۔ شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں چھوٹی مالکن۔۔۔۔۔۔آپ اس وقت پارک میں ؟
’’چاچا آپ پریشان نہ ہوں ۔ آپ دروازہ بند کر دینا میں پانچ منٹ میں آ جاؤں گی ۔‘‘ اس نے رکھائی سے کہا۔
وہ ایسی ہی تھی۔ دوسروں کے لیے دل میں بلا کی نرمی رکھنے والی۔ مگر اپنے لیے پریشان ہونے والوں سے بری طرح پیش آنے آتی ۔
اسے سب کچھ دکھاوا لگتا تھا۔
چاچا نے چاروناچار اسے باہر نکال کر دروازہ بند کیا۔ گھر کے باہر والا رستہ سنسان پڑا تھا۔ وہ باڑھ پھلانگ کر پارک میں گھس گئی۔ وہ اب اسے بنچ پر بیٹھا صاف نظر آ رہا تھا۔
اس نے دونوں ہاتھ گود میں رکھے ہوئے تھے۔ سر جھکا تھا اور شاید… اس کی آنکھیں بند تھیں۔ آنکھیں نہیں دیکھ پائی تھی وہ۔ اس نے قدم آگے بڑھایا جو اندھیرے میں پڑے ہوئے خشک پتوں پر جا پڑا۔ چرر کی آواز کے ساتھ اس نے سر اُٹھایا‘ مگر اس کی طرف دیکھنے کے بجائے گردن موڑ کے پیچھے مین روڈ پر دیکھنے لگا۔
تبھی ایک موٹر سائیکل پر سوار دو منچلوں نے ٹارچ کی روشنی میں پہلے اسے اور پھر بنچ پر بیٹھے لڑکے کو دیکھا۔
بس ایک ثانیے کے لیے اس نے ٹارچ کی روشنی میں اس کا سرخ چہرہ اور متورم آنکھیں دیکھیں تھیں۔
اور پھر منچلے سیٹی بجاتے ہوئے رفوچکر گئے۔
ان کے غائب ہونے تک وہ انہیں تکتا رہا۔
رانی اس کے قریب آ چکی تھی۔ بالکل سامنے … اس نے ایک ثانیے کی خاموشی کے بعد کہا۔
’’آئی ایم سوری۔‘‘
لڑکے کو جیسے بچھو نے کاٹ لیا۔ وہ ایک دم کھڑا ہو کر اندھیرے میں کھڑے اس کے وجود کو گھورنے لگا۔ تھوڑی دیر وہ بالکل ساکت و جامد رہا ۔
اس نے محسوس کر لیا … اس کے خوف کو۔ مگر وہ خاموشی سے اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی۔
چند گھڑیوں تک شش و پنج میں گھرا رہنے کے بعد وہ بڑی دقت سے بولا۔
ــ’’کون؟‘‘
٭…٭…٭
![]()