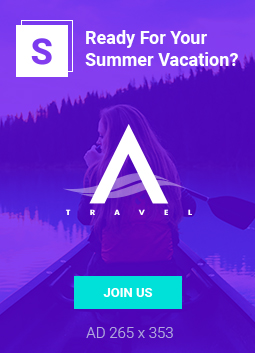وہیں میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں اس کے ساتھ مصروف ہوگئی۔ پھر ہم فاٹا چلے گئے۔وہاں حالات مختلف تھے۔ جنگ کا سماں ، گھر سے باہر نکلنا ممنوع ، پابندیاں، حالات کی کشیدگی اور دیگر چیلنجز تھے۔ میاں آگے کسی پوسٹ پر تعینات تھے۔ کبھی کبھار ہی گھر آتے۔ میں اپنے چھوٹے سے بیٹے علی کے ساتھ گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ گھر والے فون کرتے رہتے، پریشان ہوتے ، میں انہیں تسلی دیتی کہ ہم ٹھیک ہیں فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ ڈر، خوف اور پریشانی کو کبھی گھر والوں پر ظاہر نہ کیا کہ میں ایک فوجی کی بیٹی تھی۔ ہمارے والد نے ہماری تربیت فوجی انداز میں کی تھی، ہمیشہ یہ سکھایا تھا کہ ایک سپاہی کی طرح بہادری سے زندگی گزارو، اس نصیحت کو ہم نے پہلے سے باندھ لیا اور ایک سپاہی کی طرح ہر محاذ پر ڈٹے رہے یہاں تک کہ مقابل پسپا ہوگئے۔
فارغ اوقات میں میں کہانیاں لکھتی تھی اور دراز میں رکھ دیا کرتی، لکھنے کا شوق تھا۔
میں مختلف کہانیاں سوچتی ، مختلف کردار میرے ذہن میں آتے رہتے، کہانیاں بنتی اور لکھتی، اسی طرح میں نے لکھنا سیکھا۔ گھر والے فون کرتے اور کہتے کہ لاہور آجائو، میں کہتی کہ جہاں میرے میاں رہیں گے میں بھی وہیں رہوں گی۔ لاہور جانے کی خواہش پر اپنے فرج کو ترجیح دی۔
محبت کی عزت اسی میں ہے کہ وہ فرائض کو متاثر نہ کرے۔
کبھی کبھار میں اپنی ہمسائی مسز انور کے گھر چلی جاتی وہ ڈاکٹر تھیں۔ چھوٹے بچے کے ساتھ آپ کو ڈاکٹر کے مشوروں کی ضرورت رہتی ہے۔ میں ان سے بچوں کی پرورش کے طریقے سمجھتی، چھوٹے بچوں کو کیسے پالینا چاہیے، کیا کھلانا پلانا چاہیے، کون سی دوائیاں دینی چاہیے۔ بچوں کے لئے سوجی کی کھیر بنانا بھی انہوں نے ہی مجھے سکھایا۔
میں اکثر ان کی طرف چلی آتی، ہم چائے پیتے اور باتیں کرتے وہ بھی فوجی کی بیٹی تھیں، ان کے والد ریٹائر بریگیڈیر تھے۔ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بے حد سمجھدار اور دانا خاتون تھیں، ان کی معلومات حیرت انگیز تھیں۔ میڈیکل کے علاوہ انہیں بہت سے موضوعات کے متعلق علم تھا، سچی اور کھری بات کرتیں اور لوگوں کی مدد کرنے کے لئے ہر وقت تیار رہتیں۔ میں اکثر علی کو اٹھائے ان کے گھر چلی آتی، دوائیاں چاہیے ہوتی تو ان سے منگوا لیتی، اچھا ہمسایہ ایک نعمت ہوتا ہے اور ڈاکٹر ہمسائے کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔
انور بھائی اور کزئی ایجنسی میں تعینات تھے اور کبھی کبھار ہی گھر آتے۔ شمائلہ بھابھی گھر میں اپنے تینوں بیٹوں عبداللہ، عبدالرحمن اور عبدالقیوم کے ساتھ مصروف رہتیں۔ وہاں کوئی ہسپتال نہیں تھابس ایک چھوٹی سی ڈسپنسری تھی، جہاں نرسنگ سٹاف موجود تھا۔ وہ ہی اس علاقے کے ڈاکٹر تھے۔ وہ اکثر گھروں میں آجایا کرتے تھے۔ وہاں اور بھی بہت سے چیلنجز تھے۔ سوئی گیس نہیں تھی۔ بجلی کے چولہے تھے جن پر کھانا بہت دیر سے پکتا، اور پشاور سے گیس کے سلنڈر بھرواتے جاتے۔ بجلی کی فُل وولٹیج میسر نہیں تھی، ٹی وی پر جیو ٹی وی نہیں آتا تھا۔ ان دنوں عمیرہ احمدکا ڈراما میری ذات ذرہ بے نشاں جیو پر نشر ہورہا تھا، میں نے چونکہ وہ ناول پڑھا ہوا تھا اور مجھے اس ڈرامے کو دیکھنے کی شدید خواہش تھی مگر چینل نا آنے کی وجہ سے میں وہ ڈرامہ دیکھ نا سکی، فون پر دوستوں اور بہنوں سے کہانی پوچھ لیا کرتی کہ یہ بھی توسمجھوتے تھے اور یہ بھی تو قربانیاں تھیں جن کا ذکر نہیں آتا۔
پھر ایک صبح مجھے اطلاع ملی کہ شمائلہ بھابھی کے شوہر کرنل انور اورکزئی ایجنسی میں شہید ہوگئے ہیں۔ میرے پیروں تلے سے گویا زمین نکل گئی۔ میں علی کواٹھا کر فوراً ان کے گھر چلی آئی۔ بھابھی کو معلوم نا تھا کہ ان کے شوہر شہید ہوگئے ہیں۔ان کے والد نے تاکید کی تھی کہ انہیں اس بارے میں نہ بتایا جائے ورنہ وہ تین چھوٹے بچوں کے ساتھ فاٹا سے پنڈی تک سفر نہ کرسکیں گی۔ انہیں انور بھائی کے زخمی ہونے کا بتایا گیا تھا۔ انہوں نے حواس باختہ انداز میں جلدی جلدی تیاری کی ، بچوں کے فیڈر بنائے، سامان رکھوایا، کچھ سامان میں نے پیک کیا۔ ان کا بڑا بیٹا عبداللہ سمجھدار تھا اور سب کو حیرت سے دیکھتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کررہا تھا کہ یکایک یہ کیا ہوگیا ہے ماں سے سوال بھی پوچھ رہا تھا گھر سے نکلتے وقت بھابھی ہم سے ملیں، کہنے لگیں وہ جلد واپس آئیں گی، اس وقت میرا دل رو دیا اور آنکھ میں آنسو ٹھہر گئے۔ میں جانتی تھی کہ اب وہ کبھی یہاں واپس نہیں آئیں گی۔ بعض دفعہ کسی کو الوداع کہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب آپ کو مقابل سے آنسو بھی چھپانے ہوں اور مسکراتے ہوئے تسلی بھی دینی ہو۔
مسز انور کے جانے کے بعد ان کا گھر خالی ہوگیا۔ ہمسائے میں جو رونق تھی وہ ختم ہوگئی۔ میں اکثر واک کے لئے باہر نکلتی تو ان کے گھر کے سامنے کچھ دیر ٹھہر جاتی۔ یہ گھر بہت سی سنہری یادوں کا مسکن تھا۔ درودیوار سے لپٹی ویرانیوں میں کئی ان کہی داستانیں پنہاں تھیں۔
مجھے وہ منظر یاد آتا جب مسز انور یہاں سے جارہی تھیں، اپنے شوہر کے لئے، دعائیں مانگ رہی تھیں۔ یہ جانے بغیر کہ ان کے شوہر اب اس دنیا میں نا رہے تھے۔ میرے یہاں کچھ فاصلے پر کھڑے تھے، خاموش اور سنجیدہ، خاموشی سے انتظامات میں مصروف تھے۔ میں بھی اپنے بیٹے کو اٹھائے گیٹ کے پاس کھڑی تھی۔ لوگ افسردہ تھے مگر اس افسردگی کو ظاہر نا کررہے تھے۔ مسز انور کو اپنے گھر سے بہت محبت تھی جسے سجانے سنوارنے میں انہوں نے دن رات صرف کئے تھے، انہیں جلد واپس آنے کی توقع تھی۔ مگر ہم جانتے تھے کہ اب یہاں ان کی واپسی ناممکن ہے۔ کچھ حادثات انسان کو برسوں یاد رہتے ہیںکہ انسان چاہنے کے باوجود انہیں بھلا نہیں پاتا۔ کچھ عرصے بعد ہمارا بھی تبادلہ ہوگیا۔ میں ڈیڑھ سال بعد لاہور آئی تھی تو دل کی عجب حالت تھی۔ ہم موٹر وے سے آئے تھے۔ پنجاب یونیورسٹی کے سامنے سے گزرتے ہوئے میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہی عالیشان یونیورسٹی، وہی نہر، اور وہی درختوں سے بھرے ہوئے نہر کے کنارے ، ہیلے کالج کا مصروف اسٹاپ، طلبہ کا رش، مین لائبریری کا آہنی گیٹ، نیلے رنگ کی یونیورسٹی کی بس، جس میں ہمیں کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے کی خواہش ہوتی تھی۔ یونیورسٹی کا زمانہ ، بے فکری کے دن، سنہری صبحیں، چاندنی راتیں، دوستوں کے قہقہے، چائے کی خوشبو سے مہکتی کینٹین، طویل کوریڈور، جہاں آوازیں گونجتی تھیں، اساتذہ کی شفقت، وسیع و عریض کلاس روم جہاں کرسیوں پر بیٹھ کر ہم نے حصول علم کی کئی منزلیں طے کی تھیں۔ سجا سجایا آڈیٹوریم جہاں سالانہ تقریری مقابلے منعقد کئے جاتے تھے، وسیع گرائونڈ جہاں ہم گھاس پر بیٹھ کر خوش گپیوں میں مصروف رہتے اور ہنستے کھلکھلاتے رہتے، اُن دنوں ہمیں یونہی بات بے بات ہنسنے کی عادت تھی، وہ عادت کب ختم ہوگئی پتا ہی نہ چلا۔
“Nostalgia.”
ہم نے کھڑکی کے پار نظر آتے مناظر کو دیکھتے ہوئے۔ سوچاپھر وہ منظر دھندہ گئے، آنکھیں نم ہوگئیں۔
میں یادوں کے سفر پر نکل گئی۔
>
صبح سویر ے بھاگم بھاگ میں اور میری بہن فائل اور بیگ اٹھائے کتابیں تھامے یونیورسٹی پہنچتے، ساڑھے سات بجے ہماری کلاس شروع ہو جاتی تھی، اسی لئے ہمیں علی صبح جاگنا پڑتا۔ بریک میں ہم کینٹین میں بیٹھ کر ناشتا کرتے، دنیا جہاں کی باتیں کرتے، قہقہے لگاتے، کبھی کسی لڑکی کی منگنی ہوجاتی تو ساری لڑکیاں جھمگھٹا بنائے تصویریں دیکھتیں اور تبصرے کرتیں کلاسز سے فری ہوکر ہم مین لائبریری جایا کرتے، ناولز اور کتابیں ایشو کرواتے، ناول سیکشن میں میں عمیرہ احمد کے ناول تلاش کرتی ، اس وقت میں نے کبھی سوچا نا تھا کہ کبھی عمیرہ سے میری ملاقات بھی ہو گی اور وہ میری بہترین دوست بن جائیں گی۔ اچھے دوست زندگی کا اثاثہ ہوتے ہیں کہ انسان اپنی خوش قسمتی پر جتنا بھی ناز کرے کم ہوگا۔ اس وقت مجھے علم نہ تھا کہ میں بھی کبھی کوئی رائٹر بنوں گی اور میری کہانیاں اور کتابیں بھی شائع ہوں گی۔ بس لکھنے پڑھنے کا شوق تھا، کسی نہ کسی طرح پورا ہوتا رہا، یہی کافی تھا ۔ مقدر ہمیں کب ، کس سے کہاں ملادیتا ہے، یہ فلسفہ انسانی عقل سے بالا تر ہے۔ انسان کی سادگی دیکھیے، مستقبل سے کتنا انجان ہوتا ہے۔
پنجاب یونیورسٹی وہ جگہ تھی جہاں ہم نے زندگی کے بہترین دن گزارے تھے، وہ دن دوبارہ لوٹ کر پھر کبھی نہ آتے۔ آج برسوں بعد اپنی یونیورسٹی کے سامنے سے گزری تو احساس ہوا یہ جگہ کتنی قیمتی تھی۔ آج ایک بار پھر ہمیں اس یونیورسٹی کے گیٹ میں داخل ہونے کی تمنا تھی مگر مصلحتیں خواہشوں پر حاوی ہوگئیں۔
میرا بیٹا میری گود میں اُچھل رہا تھا۔
باہر کے نظارے دیکھ کر حیران اور خوش ہورہا تھا۔ کل تک میں ایک طالبہ تھی، آج میں ماں تھی، بیوی تھی، میرے ساتھ ذمہ داریاں اور فرائض تھے، مصلحتیں تھیں، سمجھوتے تھے۔ زندگی بدل گئی تھی اور وقت بھی۔ بچپن میں ہم مختلف شہروں سے لاہور آیا کرتے تو بہت ایکسائیٹڈ ہوتے تھے لاہور میں داخل ہوتے ہی مینار پاکستان اور بادشاہی مسجد کو دیکھ کر بے حد خوش ہوجاتے کہ لاہور آگیا ہے اور ہماری ساری تھکن اُتر جاتی۔ امی کی آنکھیں نم ہوجاتیں۔
امی کو لاہور سے عشق تھا، آج میں اپنی امی کے احساسات سمجھ سکتی تھی۔
ڈیڑھ سال بعد لاہور آتی تھی، امی ابو تپاک سے ملے، جب تک ہم سفر میں رہے بار بار فون کرتے رہے، انتظار کرتے رہے، والدین کی محبت کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ امی ابو خوشی خوشی میرے بیٹے کے ساتھ مصروف رہے، اسے پیار کرتے رہے، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنستے مسکراتے رہے۔
لاہور ایک دن ٹھہرنے کے بعد ہم نوابوں کے شہر بہاولپور چلے گئے۔ بہاولپور میں بہت سی پرکشش جگہیں تھیں، فرید گیٹ کا بازار، نور محل، آم اور کھجور کے باغات مگر ہمیں جب بھی موقع ملتا تولاہور ضرور آتے۔ میں سارا راستہ میاں سے پوچھتی رہتی، لاہور کب آئے گا، کتنا راستہ رہ گیا ہے۔ میاں کو لاہور کے عشق سے چڑ ہوگئی۔ تین برس بعد ہم نوشہرہ چلے گئے اور ہم نے تھوڑی بہت پشتو بھی سیکھ لی میں شام کو اپنے بیٹے کے ساتھ دریائے کابل پر چلی جاتی، وہیں سرسبز لان میں بیٹھی رہتی، کوئی مل جاتا تو اس سے گپ شپ لگ جاتی، اک اداسی سی تھی جس کے دن دیکھے سائے نظر آتے رہتے۔ شام ڈھلے گھر واپس جاتی تو میاں حیرت سے پوچھتے کہ واک پر اتنی دیر ہوگئی۔ میں جوابا ً کہتی اس شہر میں دل لگانے کی کوشش کررہی ہوں مگر کسی شہر سے ویسی محبت نہ ہوسکی جیسی لاہور سے ہے۔ وہ حیران ہوتے کہ اتنے سال ہوگئے کسی شہر میں تمہارا دل نہیں لگتا۔ ہر شہر نے لاہور کے قصے کہانیاں سنی ہیں۔ ہر شہر لاہور کے عشق کا گواہ بن گیا وہ محبت کے اس فلسفے کو سمجھنے سے قاصر تھے۔
ہر عید پر امی ابو خوش بھی ہوتے اور اداس بھی کہ دور بیاہی بیٹی کسی عید پر گھر ناآسکتی تھی۔ بہاولپور سے میں نے ابو کے لئے نیلے رنگ کا کاٹن کا سوٹ بھیجا تھا، ہر عید پر ابو وہی سوٹ پہنتے، نوشہرہ سے ابو کے لئے چترالی ٹوپی بھیجی، ساری سردیاں وہ وہی ٹوپی پہنچے رکھتے۔
ابو کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب عطا کیا تھاکہ ان کے سامنے آنے والے لوگ اس رعب کے زیر اثر آجاتے وہ کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھتے تو مقابل نظر نا اٹھا سکتا۔ بات کرتے تو سامنے والا بول نا پاتا۔ زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے مگر جب بھی بات کرتے تو جامع سنجیدہ اور ایسی بات کہتے جو سننے والوں کو برسوں یاد رہتی۔ ان کے رعب کی ہیبت مقابل کے دل پر اثر انداز ہوتی۔ ان کے پاس دین و دنیا کا علم تھا اور وہ بہترین آئی کیو لیول اور ذہانت کے حامل تھے۔ ہم نے انہیں ہمیشہ نڈر، بہادر، صابر، شاکر اور بڑی سے بڑی بات پر استقامت کا پیکر بنے دیکھا تھا۔ ایک دن میرے میاں نے انہیں میری شکایت لگائی۔ ابو سن کر ہنسے، میاں حیران ہوگئے ۔ ابو مسکراتے ہوئے بولے Have a heart(دل بڑا کرو) ان کا مطلب تھا کہ بیگم کی شکایتیں نہیں لگانی چاہیے۔
ابو نے مسکراتے ہوئے تنبیہ بھی کردی۔
میاں ورطۂ حیرت میں گھر گئے ! میں اس ردعمل کی توقع نہ تھی۔ بات کرنے کا یہ ہنر ابو کو ہی آتا تھا۔
اسی دوران میری بہن کی شادی بھی ہوگئی اور بیٹی کی پیدائش کے بعد میں راولپنڈی آگئی۔ دو بچوں کی پرورش نے زیادہ مصروف کردیا۔ میاں کی پروموشن بھی ہوگئی وہ بھی اپنی جاب میں زیادہ مصروف ہوگئے۔ پھر ایک دن مجھے فون پر یہ خبر ملی کہ ابو اب ہم میں نہیں رہے۔ کتنی دیر تک مجھے اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہ آیا۔ صدمے سے دماغ مائوف ہوگیا، گھر والوں سے کہتی رہی شاید وہ کوئی اور بندہ ہوگا جس کے بارے میں ڈاکٹرز نے یہ بتایا ہے، ہسپتال میں بہت مریض ہوتے ہیں، ڈاکٹر کو مغالطہ ہوا ہوگا۔ جب میں ان سے مل کر آئی تھی تو وہ ٹھیک تھے باتیں کررہے تھے بیمار تھے مگر اتنے تو نہیں کہ دنیاسے ہی چلے جاتے، بار بار گھر والوں سے اصرار کیا ڈاکٹر سے دوبارہ تصدیق کریں۔ گھر والے خود غم سے نڈھال تھے، انہیں اپنا ہوش نہ تھا، مجھے یقین ہی نہ آتا کہ میرے پیارے ابو اتنی خاموشی سے اس دنیا سے چلے گئے۔ کئی باتیں ان کی رہ گئیں۔ کئی داستانوں کو عنوان نہ ملے اور کئی نصیحتیں خاموش ہوگئیں۔ انہوں نے کسی کی خدمت کا احسان بھی نہ لیا۔ وہ ایک سوگوار دن تھا، اس دن تیز بارش ہورہی تھی، اک طوفان تھا، آنسو بہتے جاتے اور غم کم نہ ہوتا۔
ابو کی وصیت تھی کہ جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو اُن کی یونٹ کو اطلاع دے دی جائے اور انہیں فوجیوں کے قبرستان میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے۔
فوجی کا پہلا اور آخری عشق فوج سے ہوتا ہے، وردی سے ہوتا ہے۔ سلیوٹ سے ہوتا ہے۔ چاہے وہ سروس میں رہے چاہے ریٹائر ہوجائے۔ ایک فوجی کے لئے فوج سے جڑا تعلق سب سے قیمتی رشتہ ہوتا ہے۔ جو زندگی بھر مضبوط رہتا ہے۔ یہ رشتہ اس کی عزت و تکریم کی پہچان ہوتا ہے اور فخر کی علامت ہوتا ہے۔
وردی صرف خاکی لباس ہی نہیں بلکہ فوجی کی زندگی کا کُل اثاثہ ہوتی ہے۔
ابو کاغذات میں ریٹائر ہوئے تھے، مگر دل سے آخری لمحے تک فوجی رہے تھے، ریٹائرمنٹ دل اور وردی کے رشتے کو ختم نہیں کرپاتی۔
ابو نے ساری زندگی اس وطن کی خدمت میں صرف کردی وہ دشوار گزار جگہوں پر تعینات رہے، سرد موسم میں برف زاروں میں فرائض سرانجام دیتے رہے۔ انہوں نے صحرائوں ، دریائوں، سمندر وں کا سفر کیا اور ایسے مقامات پر فرائض سرانجام دیتے رہے جہاں مواصلاتی رابطے بھی منقطع ہوجاتے تھے۔ وہ ضرب مومن کے جانباز سپاہی تھے۔ وہ اُس زمانے میں کشمیر کے بارڈر کے محافظ تھے جب بارڈر تک سڑک تعمیر نہ ہوئی تھی۔ لوگ بذریعہ ہیلی کاپٹر جاتے یا خچرو ں پر سوار ہوکر چھ دن کی مسافت کے بعد پہنچتے۔ ابو اپنی بندوق اٹھائے جوانوں کے دستے کی سربراہی کرتے۔ جوانوں کو بھی انہیں دیکھ کر ہمت ملتی۔ جب سارا ملک چین کی نیند سورہا ہوتا تو وہ راتوں کو جاگ کر وطن کی سرحد پر پہرہ دیتے۔ اسی سرحد پر ان کے بالوں میں سفیدی اتر آئی تھی۔ بارڈر پر حالات کشیدہ رہتے ، گولہ بارود، فائرنگ ہوتی رہتی، انہیں ہر دم چوکس رہنا پڑتا۔ وطن کی حفاظت کی خاطر انہوں نے اپنا آرام تج دیا۔ برف کے موسم میں وہ کشمیر کے بارڈر پر محصور ہوگئے تھے۔ موسم کی خرابی کے باعث ہیلی کاپٹر اڑ نہ سکتے تھے۔ اس وجہ سے ابو اک طویل مدت کے لئے بارڈر کی پوسٹ پر تعینات رہے تھے۔ ہم روز ابو کا انتظار کرتے، امی یونٹ پیغام بھجواتیں مگر حالات کشیدہ تھے۔ ایک رات ابو سبز برساتی پہنے برف میں راستہ بناتے ہوئے چلے آئے۔ ان کی وردی پر جفاکشی کے نشان تھے اور کندھوں پر لگے سنہرے رنگ کے میڈل مٹیالے پڑگئے تھے۔ ان کے بالوں میں سفیدی اُتر رہی تھی اور رت جگہوں کے باعث آنکھوں کے پپوٹے سوج گئے تھے۔مگر ان کے چہرے پر سورج جیسی چمکتی مسکراہٹ تھی کہ وہ ہمیشہ کی طرح غازی بن کر اٹے تھے۔ جہاد کی فضیلت عظیم ہے، نہ غازی عام لوگ ہوتے ہیں اور نا شہید، اور کا سرحد پر پہرہ دیتے ہوئے جاگنے والی آنکھ بھی کسی عام انسان کی نہیں ہوتی۔ اس آنکھ میں دانائی ، تصوف کے رنگ اتر آتے ہیں۔ وہ آنکھ جہاں دیکھتی ہے اسیر کرلیتی ہے۔ جہاں جھکتی ہے وہاں دعائوں کا جواب آتا ہے۔ جس کی طرف اٹکتی ہے مقابل رعب کے زیر اثر آجاتا ہے۔۔ وہ آنکھ وطن کی سب سے قیمتی آنکھ ہوتی ہے۔ ابو سے ملنے والا ہر شخص ان کے اخلاق کا گرویدہ ہوجاتا۔ ہم نے انہیں کبھی کوئی نماز قضا کرتے نہ دیکھا تھا۔ گھر سے مسجد پیدل جایا کرتے تھے۔ بیماری کے باوجود کبھی روزہ قضاء نہ کیا تھا۔
جب ابوہسپتال میں ایڈمٹ تھے اسی شام ان کے دیرینہ دوست انکل اویس مصطفی راولپنڈی سے لاہور سی ایم ایچ چلے آئے۔ ابو کی وفات کے بعد انہوں نے ابو کی وصیت کو پورا کیا۔ اُن کی یونٹ والے بھی پہنچ گئے تھے۔ انہیں کیولری گرائونڈ کے قبرستان میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ ان کے انتقال کے بہت عرصے بعد تک لوگ دور دور سے آتے اور افسوس کرتے۔ وہ انسانیت کی عزت کرنے والے شخص تھے، ان کے
![]()