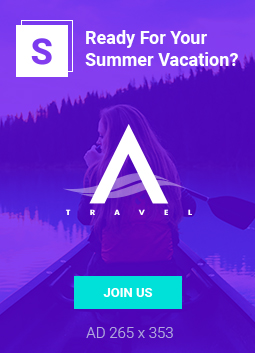مگر عیلی کو اتنے ٹھاٹ باٹ سے جاتے دیکھ آج بھی ایک آنکھ نے احساسِ کمتری میں نچڑے اشک بہائے تھے۔ وہ معصوم آنکھ رِمی کی تھی جسے دیکھ اس کے ابا پریشان ہوئے تھے۔ اب بھلا دور کوئی بھی ہو ماں باپ کے دل تو خدا ہمیشہ یک ساں ہی بنایا کرتا ہے سو ماتھے کے وہ بل تو فطری تھے۔ اس نے رِمی کی طرف قدم بڑھائے اور اس کی اداسی کی وجہ جاننا چاہی۔ اس کے لہجے میں گویا زمانے بھر کی چاشنی خود میں پیار وشفقت کا سحر سمیٹے ہوئے تھی۔ ہاں وہ پیا ر ہی تو تھا جو اس گھر میں گم نا م تھا۔۔۔ یا شاید نا محرم تھا۔۔۔ وہ دو ہی تو تھے جو اس گھر میں آپس میں اپنے الفاظ، احساسات اور بے مول جملوں کی لین دین رکھا کرتے ورنہ اِس دولت کے چمن میں کِھلنے والے گھر میں نہ کوئی بولا کرتا اور نہ رویا کرتا تھا۔۔۔ اور بولا جاتا بھی تو اپنی شان کو حاضر و ناظر رکھ کر فقط غلاموں اور نوکروں کو حکم دینے کے لئے۔۔۔ احمد کے پوچھنے پر اس معصوم کے شکوے بھرے لبوں نے احمد کی دکھتی رگوں کو برُی طرح کچلا تھا۔
“بابا سر کے پاس جب اتنی ڈھیر ساری مشینیں مو جو د ہیں، جو ا ن کے سب ہی کام کر دیا کرتی ہیں تو پھر انہیں ہماری کیا ضرورت ہیں؟ یہ سب تو وہ مشینوں سے بھی کر وا سکتے “ہیں”۔
“اِدھرا” احمد نے اسے اپنی گود میں بٹھایا۔
“رِمی یہ دنیا عجیب ہے یہاں بسنے والے لو گ اس سے بھی زیادہ عجیب ہیں۔ یہ معیاری مشینیں خود میں سے وہ لنگ کبھی ختم نہیں کر سکتیں جس کی ضرورت انسان کو ہے اور نہ ہی یہ مشینیں انسانوں کی سوچ میں کوئی ردوبدل کرسکتی ہیں۔ یہ چاہے اِن کے لئے کو ہِ نور لا دیں یا آسمانوں میں چُھپے جلتے بجھتے ستاروں کو توڑ لائیں مگر اِن کی دزدیدہ دلوں کی راحت اور رتبوں میں اضافی فٹ اور انچز تو انسانوں سے غلا می کروا کر ہی لو ٹائے جاسکتے ہیں۔ بیٹااِن مشینوں میں ہم نوکروں جیسا ظرف کہاں۔۔۔۔ جو چند پیسوں کے عو ض اِ ن کی تعریفوں میں اب تک کے پیدا ہونے والے ہر زمانے کے مجنو ں کو پیچھے چھوڑ جائے۔” احمد کی سلگتی زنگ آلود صلاحیتوں نے اس کے اندر ایک غم وغصہ بھر دیا، جو اس کی ہر بات میں پیش پیش رہا کرتا تھا اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔
“با با آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا۔” وہ بھول گیا تھا کہ وہ اپنی دس سالہ بیٹی سے مخاطب ہے۔
”ارے چھوڑوؤ یہ بتاکہ میری شہزادی اداس اداس سی کیوں بیٹھی ہے؟” اس نے رِمی کے ریشم سے ملائم بالوں کو سہلاتے ہو ئے کہا۔
“بابا مجھے بھی اِن سب کی طرح اِن مشینوں کو اپنے لئے استعمال کر نا ہے، مجھے بھی عیلی کی طرح اسکول جانا ہے گلاس ٹیبس میں پڑھنا ہے”۔ رِمی کی خواہشات سُن کر اسے بھی اپنا غربت کے کھولتے پانی میں ابلتا بچپن شدت سے یا د آیا تھا۔ جب وہ بھی اسکول جانے کو ترسا تھا، اس کے ابا بھی اسے اسکول جاتا دیکھنے کو تڑپے تھے اور اس کی ماں۔۔۔ وہ بھی اسے بھوکا دیکھ کربلکتی تھی۔ فرق تو اب بھی صرف جدت کا ہی تھا۔۔۔ وہ کاغذ قلم کو تر سا تھا اس کی بیٹی گلاس ٹیب کو ترس رہی تھی۔ احمد اپنی پھول سی بیٹی کی آنکھوں میں شبنم کی طرح بہتے گیلے موتی دیکھ کر پھر سے تڑپ رہا تھا۔
“کاش کے کوئی ایسا بھی جادو ہوتا، جو میری بیٹی کے آنسو پونچھ لیتا۔” اس نے یہ کہتے ہی رِمی کو خود سے مزید قریب کرکے سینے سے لگا لیا۔
“رِمی جب تمہارے دادا زندہ تھے وہ بھی مجھے بہت پڑھانا چاہتے تھے۔۔۔ میں بھی بہت بڑا آدمی بننا چاہتا تھا اوراِسی الف ب کی قیمت تمہارے دادا نے اپنی جوانی گنوا کر ادا کی۔ وہ میری تعلیم کے لئے کئی کئی گھنٹے پسینا بہاتے تھے اور کماکر لاتے تھے۔ انہوں نے فیکٹری میں دیگر مشینوں کے ہوتے ہوئے بھی خود مشین بن کر کام کیا، کمایااور بس۔۔۔ بس ایک سپنا سجایا۔۔۔ بس ایک۔۔۔”۔ احمد اپنی دھن میں کہے چلا جا رہا تھا کہ جدید دور میں پیدا ہونے والی اس کی سنڈریلا نے ان الفاظ کا تسلسل توڑا۔
“ابا یہ فیکٹری کیا ہوتی ہے؟”۔۔۔ اس نے ایک نظر رِمی کو دیکھا اور اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ والد کا کمزور اور جھرّیوں بدن اس کے وجود پر حاوی میں بھیگا ہو گیاتھا۔
“بیٹا پہلے مشینوں کو چلانے اور دیگر اشیا بنانے کے لئے بھی انسانوں کی ضرورت ہوا کرتی تھی اور جس جگہ وہ سب بنائی جاتی تھیں اسے فیکٹری کہتے تھے مگر آہستہ آہستہ انسان تر قی کرتے گئے اور اپنی ہی اہمیت کھو بیٹھے اور مشینوں کو بنا نے کے لئے کچھ اور مشین بنائی گئیں۔۔۔ ان کو بنانے اور چلانے کے لئے چند اور پھر۔۔۔ پھر اب آخر کا ر ایسی مشین بھی بنا لی گئی جو خود ہی چلا کرتی ہیں۔۔۔ ان کو بھی اب انسانوں کی کوئی ضرورت نہیں۔” ان جملوں کی گہرائی صرف احمد ہی جانتا تھا۔ اس کے لفظ لفظ میں اس پر بیتی یادوں کی داستان گونجتی تھی، اس کی روح میں کراہتا درد ان الفاظ کی روانی میں دھاڑیں مارتا تھا۔
“تم جانتی ہو رِمی 2014ء میں جب میں پانچویں جماعت کا طالبِ علم ہوا کرتا تھا، تب دسمبر کی ایک سرد صُبح، ملک کے کچھ غدّاروں اور دشمنوں نے مل کر شہر کے ایک اسکول پر حملہ کر دیا تھا۔وہاں پڑھنے والے ہزاروں بچے ان خون کے پیاسوں کی ہوس کی بھینٹ چڑھ گئے اورمارے گئے۔تب ہماری استانی نے ہمارے حوصلوں کو کچھ یوں پر لگائے کہ ہم سب ہی اپنی اپنی سوچوں میں اسی رفتار میں حوصلے اور جذبے کے پر لگائے اُڑان بھرنے لگے تھے۔ وہ کہتی تھی:
ہم ایسی قوم سے ہیں جس کے وہ بچوں سے ڈرتا ہے
بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے
اس یک دم پیدا ہو جانے والے جو ش وو لولے نے میری آنکھوں میں خوابوں کو پرویا تھا۔ میں سوچتا تھا بڑا ہو کر فوج میں جاؤں گا ان قاتلوں سے چن چن کر بدلہ لوں گا۔۔۔ اور ایسے ہی کئی سپنے میری نیندوں میں منڈلاتے میری اندھیری راتوں میں چاندنی بھرتے تھے۔ مگر پھر مجھے پتا لگا کہ غریبوں کے سپنوں کے تو پاؤں ہی نہیں ہوا کرتے ۔۔۔ کب ڈگ مگا جائے کب منہ کے بل گر پڑے کچھ معلوم نہیں۔۔۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔۔۔ دوسرے ہی سال2015ء کے ستمبر کے مہینے میں ہمیں پتا لگا کہ ابا جس فیکٹری میں کام کرتے تھے اب وہ جدید نظام کی نذر ہو گئی ہے اور اسے اب زیادہ مزدوروں کی ضرورت نہیں رہی ۔ اس نوکری کے بعد ابا کو بڑی مشکل سے ایک اور جگہ کام ملا مگر اس کام سے اتنی کمائی نہ ہوسکی کہ ایک وقت کی روٹی کا بندوبست کر لینے کے بعد میری پڑھائی کا بھی خر چہ نکالا جا سکتا اور اما ں تو پہلے ہی بیمار رہا کرتی سو کچھ پیسے ان کی دوائیوں میں لگ جاتے ۔ ابا کی نوکری جانے کے بعد اسکول کی فیس بھرنا چوں کہ مشکل ہو گیا تو اسکول میں روز ہی مجھے فیس لانے کی یادہانی کروائی جاتی اور میں چپ چاپ سن لیا کرتا۔۔۔ مگر مسلسل دو مہینوں تک جب فیس نہ ادا کی گئی تو ۔۔۔توپرنسپل نے مجھے خود اپنے پاس بلوا کر اچھی خاصی بے عزتی کرتے ہوئے آئندہ اسکول آنے سے منع کر دیا “۔احمد اسے سینے سے لگائے دیوار پر نظرے جمائے بولے چلے جا رہا تھا اور رِمی اسے ٹکر ٹکر دیکھتی جارہی تھی۔
“مجھے آج بھی یاد ہے جب میرا اس اسکول میں آخری دن تھا تب ہر بچہ دسمبر میں اسکول کی طرف سے منعقد کردہ تقریب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔جس میں وہ سب اُس سکول میں ہو نے والے حملے کے نتیجے میں شہید ہو جانے والے بچوں کو خراجِ تحسین پیش کرنے والے تھے اور دشمن کو پیغا م دینا چاہتے تھے کہ ہم زندہ قوم ہیں اور اِن حملوں سے ڈرنے والے نہیں ۔۔۔ میں بھی اس تقریب میں حصہ لینا چاہتا تھا ان کے ساتھ مل کر دشمن کو للکارنا چاہتا تھامگر ۔۔۔ مگر مجھے معلوم ہوا کہ اِس بار ترانہ کچھ مختلف تھا اور اسکول کی ہر دیوار اسی نئے ترانے کے سر سے رنگی گنگنا رہی تھی۔
مجھے ماں اس سے بدلہ لینے جانا ہے
مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے
میں اس ترانے کو سُن کر وہیں رک گیا ۔وہ لو گ دشمن کے بچوں کو پڑھانے کی بات کر رہے تھے۔ نہ جانے کیوں مگر دفعتاً میرے دل میں یہ خیال اُبھرا کہ کاش یہ لو گ مجھ سے بد لہ ہی لے لیتے ۔۔۔ کاش کہ مجھے بھی دشمن کا بچہ ہی سمجھ لیتے۔۔۔ کاش وہ ایسا کر دیتے تو آج تم بھی عیلی کی طرح اسکول جا رہی ہوتی۔۔۔ مگر پھر میں نے اس وقت سو چا کہ شاید اِن سب ہی کو دشمن کے بچوں کی فکر نے اتنا الجھا رکھا ہے کہ وہ اپنے ہی بچوں کو بھول بیٹھے ہیں مگر۔۔۔۔ مگر اب میں سو چتا ہوں وہ تو دراصل دشمن کے بچوں سے بھی کوئی خاص ہم دردی نہ رکھتے تھے “۔ اس نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا:
“جو اپنوں کو نہ پڑھا سکے وہ بھلا دشمن کے بچوں کو کیا پڑھاتے ۔۔۔ وہ تو فقط ایک ترانہ ہی تھا اور میں یو ں ہی الجھ گیا۔” احمد کی چند بوندیں رِمی کے چہرے کو چھوتی ہوئی اس کے گالوں پرہی جذب ہوگئیں۔
٭…٭…٭
![]()