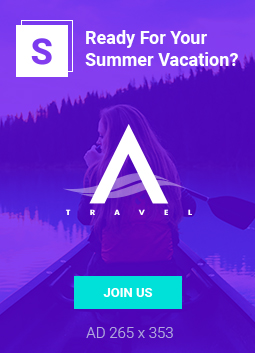ہمیں خاص طور پر کہا گیا تھا کہ ہم اس طوطے کے ساتھ باتیں کیا کریں اور اسے اچھے اچھے فقرے سکھائیں، لیکن ہم کو دیکھ کر نہ جانے اسے کیا ہو جاتا بس وہ ایک فقرے کا جاپ کرنے لگتا۔ ”میاں مٹھو ہوں”۔ ”میاں مٹھو ہوں۔” ہم اس کی حوصلہ افزائی کرتے۔ بولو مٹھو، شاباش، باتیں کرو۔ یہ کہو، وہ کہو۔ نئے نئے فقرے سکھاتے، لیکن اس کی میاں مٹھو ختم نہ ہوتی اور ساتھ ساتھ وہ ہماری طرف اس انداز سے دیکھتا جیسے جواب کا منتظر ہو۔ ہر مرتبہ کچھ اس قسم کی گفت گو ہوتی۔
”ہلو۔” وہ کہتا۔
”ہلو بھئی طوطے، سناؤ کیا حال ہے؟”
”میاں مٹھو ہوں۔” بڑے پیار بھرے لہجے میں جواب ملتا۔
”ہاں ہو۔”
”میاں مٹھو ہوں۔” چلا کر۔
”درست کہتے ہو۔”
”میاں مٹھو ہوں؟” اس مرتبہ لہجہ سوالیہ ہوتا۔
”ہو گے!”
”میاں مٹھو ہوں!” بڑی حیرانی کے ساتھ۔
”تو پھر کیا کریں؟”
”میاں مٹھو ہوں۔ میں مٹھو ہوں۔” غصے میں۔
”مان لیا بابا، مان لیا، عجب نا معقول طوطا ہے۔”
”میاں مٹھو ہوں، میاں مٹھو ہوں۔ میاں…”
اور ہم وہاں سے چلے آتے۔
کچھ سفید رنگ کی موٹی موٹی ایرانی بلیاں بھی تھیں جو اس قدر مغرور تھیں کہ کسی کو خاطر میں نہ لاتی تھیں۔ البتہ ایک چھوٹی سی بلی بڑی ذہین اور سمجھ دار تھی۔ وہ صبح صبح ہمیں جگانے آتی۔ چپکے سے پلنگ پر چڑھ کر پاؤں میں ہلکی سی گدگدی کرتی… جگا کر ایک کونے میں انتظار کرتی کہ کہیں ہم دوبارہ نہ سو جائیں۔
بڑے کمرے میں کچھ قالین تھے، اتنے خوب صورت کہ انہیں فرش پر دیکھ کر ہمیں بڑا افسوس ہوتا۔ وسط میں جو بڑا قالین تھا اس کا کچھ حصہ جل گیا تھا، اس طرح کہ وہاں پر نہ صوفہ رکھا جا سکتا تھا نہ کوئی میز۔ جب کبھی مہمان آتے تو وہی عقل مند بلی اس جلے ہوئے حصے پر بٹھا دی جاتی۔ وہ کچھ اس انداز سے وہاں بیٹھتی جیسے اسے کسی کی بھی کچھ پروا نہیں ہے۔ اسے لاکھ بلاتے، بہلاتے، پھسلاتے، پیار کرتے، لیکن وہ وہاں سے تب تک نہ ہلتی جب تک وہ سب چلے نہ جاتے۔ باہر والوں میں سے کسی کو پتاتک نہ تھا کہ ہمارا خوب صورت قالین جلا ہوا ہے۔
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
ان دنوں رُوفی اور میں اُوپر کے کمرے میں رہتے تھے کیوںکہ روفی کا خیال تھا کہ سطح سمندر سے زیادہ بلندی کی وجہ سے اس کی آب و ہوا بہتر ہے۔
ٹیوشن شروع ہو گئی۔ دن بھر سکول میں رہتے۔ شام کو ماسٹر صاحب تشریف لاتے جو چلتے وقت فالتو کام دے جاتے۔ جس کے لیے دیر تک جاگنا پڑتا۔ بعض اوقات روفی کے ابا ہمیں سیر پر لے جاتے اور راستے بھر انواع و اقسام کی ہدایتیں ملتیں… یہ کرو، یہ مت کرو، اگر یوں کرو تو یوں ضرور کرو اور اگر یوں نہیں کرتے تو یوں بھی مت کرو۔ ایک روز انہوں نے ہمیں کلب جانے کو کہا۔ بولے ”اس طرح تمہاری معلومات میں اضافہ ہو گا اور گفت گو کرتے وقت اب جو جھجک محسوس ہوتی ہے وہ دُور ہو جائے گی۔” چناںچہ ہم کلب گئے۔ جا کر دیکھتے کیا ہیں کہ ایک بہت بڑی سجی سجائی عمارت سنسان پڑی ہے اور ایک لمبے سے کمرے میں بہت سے معمر حضرات بالکل بے زار بیٹھے ہیں۔ ہم ایک کونے میں چوروں کی طرح کھڑے تھے کہ انجینئر صاحب نے بلایا اور پاس بٹھا لیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی پھر انہوں نے کہا۔ ”بھئی لڑکو! کچھ بات چیت کرو۔” میں نے روفی کی طرف دیکھا۔ انہوں نے میری طرف اشارہ کیا۔ میں نے گلا صاف کیا اور سوچنے لگا کہ کیا کہوں۔ چند روز پہلے ہم نے سنا تھا کہ شاہ امان اللہ خان نے تخت چھوڑ دیا ہے۔ چلو اسی سے گفت گو شروع کرتے ہیں۔
”وہ سنا آپ نے… امان اللہ خاں نے تخت چھوڑ دیا۔”
”اچھا؟ کب؟” انجینئر صاحب نے پوچھا۔
”کچھ دن ہوئے۔”
ان کی بغل میں جو صاحب بیٹھے تھے بولے۔ ”کس نے تخت چھوڑ دیا؟”
”جی، امان اللہ خاں نے۔”
”افوہ!” کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔
”کیا ہوا؟ کون تھا؟” ایک صاحب جو ان کے بالکل قریب بیٹھے تھے کہنے لگے۔
”جی امان اللہ خاں نے تخت چھوڑ دیا۔”
”اوہ!”
ان کے سامنے بیٹھے ہوئے صاحب کچھ دیر کے بعد چونک کر بولے۔
”یہ کن صاحب کا ذکر ہو رہا ہے؟”
”جی امان اللہ خاں کا۔”
”نہیں کیا ہوا؟”
”انہوں نے تخت چھوڑ دیا۔”
”اچھا!”
”بھئی یہ اکیلے ہی اکیلے کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں بھی تو بتاؤ۔” ایک طرف سے آواز آئی۔
”جی، امان اللہ خاں نے تخت چھوڑ دیا۔”
”افوہ، بڑا افسوس ہوا۔ کون تھے وہ؟”
”جی بادشاہ تھے۔”
”کہاں کے؟”
افغانستان کے۔”
”اچھا۔”
میرے داہنے ہاتھ بیٹھے ہوئے صاحب یکلخت اُچھل پڑے۔ ”کیا کسی نے تخت چھوڑ دیا۔”
”جی ہاں۔”
”کس نے؟”
”امان اللہ خاں نے۔”
”اوہ، امان اللہ خاں نے۔”
کچھ دیر خاموشی رہی۔ پھر سامنے کے صوفے پر ایک صاحب ہڑ بڑا کر اُٹھے۔
” یہ کوئی کسی کے کچھ چھوڑ دینے کا ذکر کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟”
”جی، امان اللہ خاں نے تخت چھوڑ دیا۔”
”ارے۔”
غرض یہ کہ اسی طرح باری باری ہر شخص نے پوچھا کہ کیا ہوا اور مجھے کوئی پچاس مرتبہ بتانا پڑا کہ امان اللہ خاں نے تخت چھوڑ دیا۔ ہم نہایت بے زار ہو کر واپس لوٹے۔ گھر میں یہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جھیل کی باتیں شروع ہو گئیں۔ مچھلیوں کے متعلق ان کے شبہات بدستور موجود تھے۔ ہم نے بڑے وثوق سے کہا کہ وہ بڑی بڑی مچھلیاں ہیں۔ ہم اکثر پکڑتے رہے ہیں۔ ہم نے کئی مرتبہ انہیں بھونا جبھی ہے۔ بولے۔ اچھا اس مرتبہ پکڑو، تو گھر لانا ہم بھی چکھیں گے۔
اگلے اتوار کو ہم صبح سے شام تک پانی میں بنسیاں ڈالے بیٹھے رہے، لیکن کچھ نہ ملا۔ واپسی پر بازار میں مچھلی والے سے بڑی بڑی مچھلیاں خریدی گئیں اور باورچی کے حوالے کی گئیں۔ اتفاق سے اس شام کو سب کہیں باہر مدعو تھے۔ گھر میں صرف میں اور روفی تھے اور ایک بزرگ جو ننھے میاں کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا کرتے۔ رات کے وقت بزرگ کو اچھی طرح دکھائی نہ دیتا تھا۔ ننھے میاں پہلے تو دستر خوان پر بیٹھتے پھر چپکے سے اُٹھ جاتے۔ اُدھر بلیاں قطار باندھے کیو لگائے منتظر ہوتیں اور بڑے اطمینان سے ساتھ آبیٹھتیں۔ وہ یہی سمجھتے کہ ننھے میاں ساتھ بیٹھے ہیں، چنانچہ وہ بار بار بلیوں سے کہتے۔ برخوردار بھوکے مت رہنا۔ چیزیں اٹھا اٹھا ان کے سامنے رکھتے۔ یہ چکھو برخوردار۔ یہ بھی کھاؤ برخوردار… ادھر بلیاں بڑے سکون سے کھاتیں۔
چنانچہ ہماری خریدی ہوئی مچھلیاں اس رات بلیوں نے کھائیں۔ اگلی مرتبہ ہم جھیل پر گئے اور واپس آتے وقت مچھلیاں خرید کر لائے تو نہ جانے کس کے مشورے سے مچھلیاں ڈاکٹر صاحب کے ہاں بھیج دی گئیں۔ اس سے اگلی مرتبہ انجینئر صاحب کے ہاں۔ پھر ایک روز کیا ہوا کہ سب کے سامنے مچھلی والا حساب لے کر آگیا۔ ہمارا جیب خرچ ختم ہو چکا تھا اور مچھلیاں اُدھار آرہی تھیں۔ سب کو پتا چل گیا۔ ہمارا خوب مذاق اُڑا۔ ہمیں ہدایت کی گئی کہ آئندہ جھیل پر نہ جایا کریں۔ ہم وہاں محض وقت ضائع کرنے جاتے ہیں۔ جب وہاں مچھلیاں ہیں ہی نہیں تو جانا بالکل بے سود ہے۔
ہم سکول کا کام کر رہے تھے۔ رستم ہمارے پاس بیٹھا تھا۔ ہمارے دل میں بار بار یہی خیال آتا تھا کہ وہاں جانا بے سود کیوں ہے۔ رستم کہہ رہا تھا۔ لڑکو جب تم بڑے ہو جاؤ گے تب تمہیں معلوم ہو گا کہ دنیا میں جس کام سے کسی فائدے کی اُمید نہیں ہے وہ بے سود ہے۔ دنیا میں لوگ صرف وہی کام کرتے ہیں جس میں نفع ہو۔ صرف ان لوگوں سے ملتے ہیں جو فائدہ پہنچا سکیں۔ صرف وہ باتیں سوچتے ہیں جو سود مند ہوں۔ باقی کے سب کام، سب انسان اور سب باتیں بے کار ہیں۔
اگلے اتوار کو سب کہیں باہر جا رہے تھے ہمیں حکم ملا کہ ہم دن بھر گھر کی رکھوالی کریں گے۔ چھوٹے ننھے، ننھے میاں، ٹیلی فون اور ملاقاتیوں کا خیال رکھیں گے اور ماسٹر صاحب نے ہمیں گھوڑے پر جواب مضمون لکھنے کو کہا تھا۔
میں اور روفی کمرے میں کاپیاں لیے بیٹھے تھے۔ ایک کونے میں ننھا کھیل رہا تھا۔ ننھے میاں پڑوس کے بچوں کے ساتھ تھے۔ رستم پوچھنے لگا۔ ”کیا لکھ رہے ہو؟” ہم نے بتایا۔ ”گھوڑے پر جواب مضمون۔” وہ بولا۔ ”یوں بھی کبھی مضمون لکھے گئے ہیں۔ سوال مضمون ہو یا جوابِ مضمون، جس چیز پر لکھنا ہو اُسے دیکھ کر لکھو میں ابھی گھوڑا لاتا ہوں۔” وہ گھوڑا لے آیا۔ ”اب اس پر سوار ہو کر لکھو۔ تمہیں گھوڑے ‘پر’ جواب مضمون لکھنا ہے۔”
وہ گھوڑا بہت اُونچا تھا۔ ہم زینے پر کھڑے ہو گئے۔ رستم گھوڑے کو کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بڑی مشکل سے گھوڑا نزدیک آیا، ابھی روفی نے اپنا پاؤں اس پر رکھا ہی تھا کہ وہ آگے چل دیا۔ کئی مرتبہ اسی طرح ہوا۔ آخر طے ہوا کہ گھوڑے پر سیڑھی لگا کر چڑھا جائے۔ رستم بولا۔ اگر تم دونوں نے اس گھوڑے پر چڑھ کر مضمون لکھا تو دونوں کا مضمون ایک سا ہو گا۔ میں ایک اور گھوڑا لاتا ہوں۔ ہم نے کہا۔ نہیں یہی کافی ہے۔ بہ مشکل رُوفی گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اس قدر ڈرے ہوئے تھے کہ رستم کو بھی ساتھ بیٹھنا پڑا۔ میں نے انکار کر دیا۔ دیکھتے دیکھتے گھوڑا بدک کر سرپٹ بھاگا۔ رستم نے چار یا پانچ نہایت اعلیٰ درجے کی نفیس قلابازیاں کھائیں اور رُوفی نے کسی کہنہ مشق نٹ کی طرح تماشا دکھایا۔
کپڑے جھاڑتے ہوئے رُوفی ستم سے بولے۔ ”گھوڑے پر ان دونوں سواریوں کا شکریہ۔”
”دو سواریاں کیسی؟”
”میری پہلی اور آخری سواری۔”
باورچی کو کہا گیا تھا کہ وہ ننھے کا خیال رکھے۔ چنانچہ وہ ہر دس پندرہ منٹ کے بعد باورچی خانے کی کھڑکی سے سر نکال کر ننھے کی طرف دیکھے بغیر چلاتا تھا۔ ”ننھے یوں مت کرو!” ”خبردار ننھے جو یہ کیا ہے تو!”
پھر یکایک ننھے کے رونے کی آواز آئی۔ ہم بھاگے بھاگے پہنچے۔ ”ننھے کو چوٹ کیوںکر لگی؟” ہم نے باورچی سے پوچھا۔
”وہ سامنے سیڑھیاں دیکھیں آپ نے؟”
”ہاں۔”
”بس وہ ننھے نے نہیں دیکھیں۔”
ہم نے اسے چپ کرانے کے لیے بہتیرے جتن کیے۔ آخر رستم نے مشورہ دیا کہ اسے گائے کا دودھ پلایا جائے۔ باورچی دودھ لایا۔ ہم نے اس سے پوچا۔ ”یہ تازہ تو ہے نا؟”
”تازہ؟ چند گھنٹے پہلے یہ سبز گھاس تھا۔” اس نے فوراً جواب دیا۔
ننھے نے چکھا لیکن پینے سے انکار کر دیا۔ معلوم ہوا کہ دودھ پھیکا تھا۔ باورچی سے شکر ملانے کو کہا گیا۔ اس نے گھر چھان مارا، لیکن شکر نہ ملی۔ رستم نے کہا۔ ”ابھی صبح پانچ سیر شکر آئی تھی۔ باورچی خانے میں میں نے خود دیکھی ہے۔”
باورچی مسکرایا اور بولا۔ ”افوہ! مجھے یاد آیا۔”
اندر گیا۔ کچھ دیر میں خالی ہاتھ لوٹا۔ ”وہاں تو نہیں ملی۔”
”تو پھر کہاں گئی؟”
”کسی کتے بلی نے کھالی ہو گی۔” وہ بولا۔
اندر جا کر دیکھتے ہیں تو ایک بالکل چھوٹا سا کتا خوابِ خرگوش سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اسے جگانے سے پہلے میں نے پوچھا۔ ”کیا کتے شکر کھاتے ہیں؟”
”اور کتوں کو تو پتا نہیں، یہ کتا بے حد چٹورا ہے۔ میٹھی چیز تو یہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ ضرور اسی نے شکر کھائی ہے۔ اسے تول کر دیکھ لیجیے۔”
کتے کو جگایا گیا۔ ترازو منگائی گئی۔ اسے تولا گیا۔ وہ پورا پانچ سیر تھا۔
”شکر کا وزن تو پورا ہو گیا۔” رُوفی نے باورچی سے پوچھا۔ ”اب کتا کہاں گیا؟”
باورچی سے جب کئی اور سوال پوچھے گئے تو وہ بولا۔ میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں جتنا کہ دکھائی دیتا ہوں۔
”کاش کہ تم ہوتے۔” رستم نے کہا۔
اتنے میں ننھے میاں آگئے۔ ننھے میاں خود ساڑھے چار سال کے تھے اور چھوٹے ننھے سے دو سال بڑے تھے۔ ہم نے ان کی خوشامد کی کہ چھوٹے ننھے کے ساتھ کھیلو۔ انہوں نے بڑی حقارت سے ننھے کی طرف دیکھا اور بولے۔ ”اس کے ساتھ؟ اونہہ، یہ تو بچہ ہے۔”
ننھا خوب رو رہا تھا۔ آخر ہم نے تنگ آکر ریڈیو لگا دیا اور اسے اتنا بلند کر دیا کہ ننھے کی آواز دب کر رہ گئی۔ دفتر سے اس طوطے کو نکال کر ریڈیو کے سامنے بٹھا دیا۔ سیاہی سے ننھے میاں کی ڈاڑھی اور مونچھیں بنائی گئیں۔ بلیوں کے منہ پر پاؤڈر، سرخی اور لپ سٹک لگائی گئی۔ کتے کے گلے میں سفید کالر اور نہایت بڑھیا ٹائی باندھی گئی۔ سر پر ہیٹ اُڑھایا گیا۔ گھوڑے کے سر پر کلاہ رکھ کر صافہ باندھا گیا۔
فون آیا… رُوفی نے ریسیور اٹھایا اور ننھے کے منہ کے سامنے کر دیا۔ ننھا خوب مزے لے کر رو رہا تھا۔
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
![]()