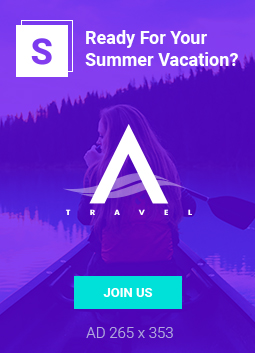میرے اُستاد محترم!
اُمید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے مل کر آیا ہوں اور ابھی تک سحرزدہ پھر رہا ہوں۔ پیرس فیشن ویک میں شرکت کے لیے پیرس آیا ہوا ہوں اور ہر شام شانزے لیزے پر دُنیا کی چکاچوند میں سے گزرتے ہوئے آپ کو یاد کرتا ہوں۔
خوب صورت عورتوں کے ہجوم میں مہنگے ترین برانڈز کی یلغار میں دُنیا کی اس بھیڑ میں سکون صرف اس تخلیق میں ہے جو آپ کرتے ہیں، وہاں ترکی کے اس چھوٹے سے گھر کی خاموشی اور سکون شانزے لیزے کی اس چکاچوند پر بھاری پڑتی ہے۔
آپ کے پاس اس گھر میں بیٹھ کر مجھے نہ پیرس یاد آتا تھا، نہ میلان مگر یہاں اس دنیا میں گھومتے ہوئے آپ کی باتیں اور آپ کی خطاطی میرے ساتھ گھومتی ہے، میرا سایہ بن کر۔ نہ میں کان بند کر سکتا ہوں نہ آنکھیں کر بھی لوں تو کیا فرق پڑے گا، آپ تو کہیں دل اور دماغ کا حصہ بن گئے ہیں۔ یا شاید روح کا۔
بڑا غلط کیا آپ نے اسے بیدار کر کے۔ اب یہ اس ہجوم کے بیچ میں رہنا نہیں چاہتی جہاں میں رہتا ہوں، مجھ سے اپنے جیسوں کی محبت مانگتی ہے۔ وہ میں اسے کہاں سے لا کر دوں عبدالعلی صاحب؟ میں تو آپ کے علاوہ کسی دوسرے کو جانتا ہی نہیں جس کے پاس یہ خوش ہو جائے اور اسے خوش کرنے کی تلاش میں نکلوں گا تو دنیا چھوڑنی پڑے گی، وہ میں چھوڑ نہیں سکتا کیوں کہ اس ”دنیا” کو پانے کے لیے میں نے بہت محنت کی ہے۔ اس دنیا کو پاکر کھو دینے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے۔ آپ تو مومن ہیں، آپ نے کبھی ”دنیا” کی تمنا کی ہی نہیں۔ وہ بار بار چل کر آپ کے پاس آئی بھی تو آپ نے اپنی روح کے دروازے بند رکھے۔ مگر آپ کسی ایسے کو جانتے ہیں جو دنیا کو پاکر اسے خود کھودے؟ کوئی ایسا ملے تو مجھے ضرور ملوائیں اُس سے۔ ابراہیم کی مشکل شاید وہ ہی آسان کر دے۔
اس بار آپ کو دیکھ کر دل بڑا بوجھل ہوا، شاید اس لیے بھی زیادہ یاد آرہے ہیں آپ۔ آپ کو غم زدہ اور رنجیدہ دیکھ کر مجھے اپنے ماں باپ یاد آتے رہے۔
میں نے پہلی بار جانا، میرے یورپ آجانے اور پیچھے سارے رابطے ختم کر دینے کے بعد وہ کیسے تڑپتے ہوں گے۔ طہٰ تو مر گیا، مگر میں نے تو زندہ ہوتے ہوئے بھی انہیں ترسا دیا۔ پتا نہیں کیا ہوا تھا عبدالعلی صاحب کہ یورپ آکر پیچھے رہ گئے رشتوں کو بھول ہی گیا تھا میں۔ گاؤں، گھر، ماں، باپ، بہن، بھائی، سب۔ آزاد پرندہ بن کر جینا چاہتا تھا میں، پر یہ یاد ہی نہیں رہا تھا مجھے کہ آزاد پرندہ اُڑتا آسمان میں ہے مگر گھونسلہ وہ بھی درخت پر ہی بناتا ہے جس کی جڑیں مٹی میں ہوتی ہیں۔
آپ کے طہٰ کے لیے غم کو دیکھ کر مجھے اپنے ماں باپ نہیں بھول رہے۔ آپ ظالم نہیں تھے پر میں ظالم تھا۔ ظالم کو اپنے ظلم کا احساس ہو پر تب تک مظلوم ہی نہ رہے تو پھر ظالم کیا کرے؟ میرے ماں باپ سالوں پہلے دنیا سے چلے گئے اور مجھے احساسِ زیاں آج ہو رہا ہے۔ اب اگر توبہ بھی کروں تو کس منہ سے کروں؟
میرا دل چاہتا ہے، میں آپ سے آپ کا غم بانٹ لوں۔ کاش غم کوئی چیز ہوتا جو میں آپ سے لے کر کہیں دور پھینک آتا۔
میں نہیں جانتا، آپ کا پچھتاوا کیا ہے جس کا بار بار ذکر کر کے آپ چُپ ہو جاتے تھے مگر میں یہ بھی نہیں جانتا، طہٰ آپ کے پاس کیوں واپس نہیں آیا مگر میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ اس نے جو کیا کیوں کیا ہو گا۔ پیار بہت کچھ بھلا دیتا ہے۔۔۔ رب سب سے پہلے۔۔۔ ماں باپ اس کے بعد۔۔۔ دنیا سب سے آخر میں۔۔۔ میں گزرا ہوں اس راستے سے۔ ۔۔اس کے سب نشیب جانتا ہوں اور فراز تو اس راستے میں کہیں ہے ہی نہیں اس کا کیا ذکر کروں۔
طہٰ کی بدقسمتی بس اتنی کہ اس کی قسمت میں شوبزنس کی عورت لکھی تھی۔ میں پاکستان کے شوبزنس کو نہیں جانتا۔ اٹلی اور یورپ کے شوبزنس کو جانتا ہوں۔ شوبزنس کی عورت میں حیا نہیں رہتی۔ یہ اس پیشے کی مجبوری ہے پر وفا کیوں نہیں ہوتی؟ یہ وہ خود بھی نہیں جانتیں۔ طہٰ نیک روح تھا، بھٹک گیا۔ شوبزنس بڑی ظالم دنیا ہے اور اس دنیا سے جڑنے والے بھی۔ یہ سراب بن کر نظروں کو بہکاتا ہے اور تب تک بہکاتا ہی رہتا ہے جب تک انسان اندھا نہ ہو جائے۔
آپ کی بہو ایک بُری عورت تھی، اس لیے آپ کے لیے آزمائش بن کر آئی لیکن عبدالعلی صاحب یہ آزمائش آپ کی زندگی میں نہ آتی تو آپ کا مرتبہ کیسے بڑھتا۔ نیکوں کے راستے میں آزمائشیں آتی ہیں اور بُروں کے راستے میں مخمل۔ یہ آپ ہی نے کہا تھا نا مجھے؟
اُستاد محترم! آپ کی باتیں آپ ہی کو لکھتے ہوئے شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ پر کیا کروں، آپ کو دلاسا دینا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میرے پاس لفظوں کے علاوہ اور کچھ نہیں۔
اگر میں کچھ کر سکتا ہوں آپ کے لیے تو مجھے حکم دیجئے۔ سید ابراہیم اُڑتا ہوا آئے گا۔ آپ کا بیٹا نہیں بن سکتا مگر آپ کا فرماں بردار ضرور ہو سکتا ہوں۔
ایک گمراہ
سید ابراہیم
٭…٭…٭
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
وہ میز بہت سارے کاغذات سے بھری ہوئی تھی اور ان کاغذات میں کیا کیا تھا، کوئی پہلی نظر میں جان بھی نہیں سکتا تھا۔قلبِ مومن نے اس میز پر ہمیشہ کھانا دیکھا تھا یا قہوہ یا پھر اخبار مگر اب ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز دوبارہ اس میز پر نہیں آنے والی تھی۔
وہ کتنے دن سے وہاں اس گھر میں تعزیت کے لیے آنے والوں سے مل رہا تھا۔ وہ گنتی بھول گیا تھا۔ وہ کتنے دن سے وہاں آنے والی ڈاک بغیر کھولے اس میز پر ڈھیر کرتا جا رہا تھا۔ اسے یہ بھی یاد نہیں تھا۔ وہ غم میں نہیں تھا وہ حیرت میں بھی نہیں تھا۔ وہ صرف یہ بوجھنے کی کوشش کر رہا تھا اور کسی سوال کا کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔
اس نے آخری بار انہیں آئی سی یو میں دیکھا تھا اور اس کے وہاں پہنچنے کے چند گھنٹوں بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اس ہاسپٹل میں ان کو ان آخری چند گھنٹوں میں ملنے کے لیے آنے والا واحد شخص نہیں تھا۔ وہ ہاسپٹل اس کے آنے سے پہلے عبدالعلی کے ان شاگردوں سے بھرا ہوا تھا جو ان کے ہاسپٹل میں ہونے کا سن کر پتا نہیں کہاں کہاں سے آئے تھے اور قلبِ مومن کا عبدالعلی سے رشتہ جان کر اس سے تعزیت کرنے لگے تھے۔
قلبِ مومن کا خیال تھا، اسے اب عبدالعلی کی تدفین کے انتظامات کرنے پڑیں گے۔ اسے یہ بھی نہیں کرنا پڑا تھا۔ اسٹیٹ کی طرف سے ان کی آخری رسومات ادا کی جا رہی تھیں اور اس سب میں قلبِ مومن کی جیسے کوئی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ وہ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا تھا۔ ایک خاموش تماشائی کے طور پر۔۔۔ یا شاید اچنبھے میں آجانے والے تماشائی کے طور پر۔
انہیں اپنی زندگی میں قلبِ مومن کی ضرورت شاید رہی ہو۔ موت کے بعد نہیں رہی تھی۔ وہ مجمع جو انہیں دنیا سے رخصت کرنے کے لیے آیا تھا وہ کہاں کہاں سے آرہا تھا اور کیوں آرہا تھا۔ قلبِ مومن ششدر تھا۔ وہ جانتا تھا۔ عبدالعلی نامور خطاط تھے مگر وہ ناموری کتنی تھی۔ قلبِ مومن نے اتنے سالوں میں یہ کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی اور اب جب وہ ان کا مقام دیکھ رہا تھا تو وہ ششدر تھا۔
آدھی رات کو وہ اس میز پر پڑے ان لفافوں کو باری باری کھولنے لگا تھا۔ وہ مختلف ممالک کے کلچر منسٹریز کی طرف سے آئے ہوئے تعزیتی پیغامات تھے۔ دنیا کے بڑے بڑے آرٹ میوزیمز اور گیلریز سے آئے ہوئے تعزیتی خطوط۔ عبدالعلی کا کام کہاں کہاں نہیں رکھا ہوا تھا اور وہ ان کا اکلوتا پوتا اس سب سے بے خبر تھا۔
اس گھر میں رات کے اس پہر عجیب سی خاموشی تھی اور اس خاموشی میں اگر کچھ تھا تو کاغذ کی آوازیں یا آتش دان میں چٹختی لکڑیوں کی آواز۔
قلبِ مومن نے ہاتھ میں پکڑا وہ سرکاری خط میز پر رکھ دیا جس میں حکومت جاپان نے عبدالعلی کے لیے بعد از مرگ ایک سول ایوارڈ دینے کی اطلاع دی تھی۔ اس خط میں اس سے پہلے دیے جانے والے ایک اور ایوارڈ کا ذکر بھی تھا اور اس گھر میں قلبِ مومن نے کبھی کہیں ان ایوارڈز میں سے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ اس گھر کی دیواروں پر مکمل اور نامکمل خطاطی کے نمونوں کے علاوہ کچھ اور تھا ہی نہیں۔ قلبِ مومن کے اپارٹمنٹ کے برعکس جو اس نے ہر اس ”ثبوت” سے سجا رکھی تھیں جو دنیا نے اسے اس کی نام وری کے لیے دیے تھے۔ اشتہار کی طرح۔
اور اس ہی اپارٹمنٹ میں کھڑے ہو کر وہ عبدالعلی سے پوچھتا رہا تھا کہ انہیں ان کے کام نے اتنے سالوں میں کیا دیا اور عبدالعلی بغیر گنوائے چپ کھڑے اس کی باتیں سنتے رہے تھے اور اب ان کے جانے کے بعد ان کے سامان میں قلبِ مومن وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جو دنیا نے انہیں دیا تھا۔
وہ کتنے دن اور کتنی راتوں سے نہیں سویا تھا، وہ جیسے گنتی بھول گیا تھا۔ اسے عبدالعلی کے بارے میں سوچنے کا بھی موقع نہیں ملا تھا۔ رونے کا بھی نہیں۔ پچھتانے کا بھی نہیں اور اب اتنے دنوں کے بعد رات کے اس پہر میں وہ جیسے یہی سارے کام کر رہا تھا۔
”تو دادا! یہ تھے آپ۔۔۔ اور میں قلبِ مومن کبھی آپ کو جان ہی نہیں پایا۔۔۔ یا آپ نے جاننے دیا ہی نہیں۔”
ایک کے بعد ایک لفافہ کھولتے، ان تعزیتی پیغامات پر نظر ڈالتے قلبِ مومن نے سن ذہن کے ساتھ سوچا تھا۔
”مجھے ساری دنیا جانتی ہے۔۔۔ آپ کو کون جانتا ہے۔۔۔آپ نے زندگی کے اتنے سال جس کام کو دیے اس نے آپ کو کیا دیا؟ اور مجھے دیکھیں۔۔۔ مجھے کون نہیں جانتا۔” اس نے دادا سے کہا تھا۔
Lourve میوزیم میں اُس ہفتہ کو The Last Master of Mohaqqiq کے نام کیا گیا تھا۔ قلبِ مومن نے ہاتھ میں پکڑے اس اطلاع نامہ کو بھی بے حد خاموشی کے ساتھ کاغذوں کے اسی ڈھیر پر رکھ دیا جنہیں کھولتے کھولتے اس کے ہاتھ تھکنے لگے تھے۔
Lourve سے برٹش میوزیم، برٹش میوزیم سے اقوامِ متحدہ کی جنرل اسمبلی۔ عبدالعلی کا کام ہر جگہ موجود تھا اور اب ان کے کام کی تصاویر اخبارات کے اس ڈھیر میں مختلف ہیڈنگز کے ساتھ تھیں جو اس گھر میں سالوں سے آتا اور اتنے دنوں میں جمع ہوتے ہوئے ردی کے ایک ڈھیر کی شکل اختیار کر گیا تھا اور اس ردی کے ڈھیر کو قلبِ مومن اب کھنگال رہا تھا۔ اس شخص کے بارے میں جاننے کے لیے جس کو اس نے ساری عمر جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔
وہ اسے ترکی کے بہترین بورڈنگ اسکول میں پڑھانا کیسے افورڈ کر پائے تھے۔ اسے امریکہ کی اس مہنگی ترین یونیورسٹی میں کیسے پڑھاتے رہے تھے۔ قلبِ مومن کو آج اندازہ ہوا تھا۔ عبدالعلی کے لیے ”دنیا” جمع کرنا اتنا آسان تھا۔ چٹکی بجاتے جتنا۔ اور وہ پھر بھی اس کی طرح اس پینٹ ہاؤس میں نہیں رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی اسی لکڑی کے چھوٹے سے گھر میں گزار دی تھی۔ وہ سارے ایوارڈز جو انہیں دنیا بھر کی حکومتوں اور آرٹ ایسوسی ایشنز کی طرف سے ملتے رہے تھے، وہ اسی گھر میں پڑے چند بکسوں میں بند تھے۔ دھول مٹی اور جالوں میں اٹے ہوئے۔ یوں جیسے لینے والے نے اپنے اُن اعزازات کو کبھی کھول کر دیکھا تک بھی نہ ہو۔ وہ گھر زندگی میں پہلی بار قلبِ مومن کے لیے بھول بھلیاں بن گیا تھا۔ وہاں پڑی ہر چیز عقل کو خیرہ کرنے والی اور اس گھر کا جانے والا مالک اس کو سارے جواب دیتے ہوئے گونگا کر گیا تھا۔
وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دیواروں پر لگی کیلی گرافیز کو اس نے پہلی بار بغور دیکھنا شروع کیا۔
”اور میں قلبِ مومن ”عزت” اور شہرت میں کبھی تمیز ہی نہیں کر سکا۔ نام اور ناموری کا فرق ہی نہیں پہچان سکا۔ کامیابی کا مفہوم ہی نہیں سمجھ پایا۔”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
![]()